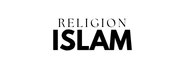محترم بھائی/بہن،
وقت ہوتا ہے،
تاہم، وقت کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے۔
جبکہ ہماری دنیا میں وقت ایک مختلف رفتار سے چلتا ہے، خلا میں اس کی رفتار مختلف ہے۔ ہماری دنیا کا ایک سال سورج کے ایک لمحے کے برابر ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا ایک دن بعض مخلوقات کے لیے ایک پوری عمر کے برابر ہے۔
وقت،
کیا زندگی سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک کے ان "لمحوں” کا ایک سلسلہ ہے جو نبض کی طرح دھڑکتے رہتے ہیں؟
یا کیا یہ وقت اور کیلنڈر کے حساب سے کوئی چیز ہے؟ اس کا مطلب جو بھی ہو، وقت کے وہ راز جو ہمیں بوڑھا کرتے ہیں اور موت کی طرف لے جاتے ہیں، ان موضوعات میں سے ایک ہیں جو ہماری سب سے زیادہ توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔
ہم اس جگہ کو، جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے، اور وقت کو ایک گھڑی کے طور پر، مادہ اور وقت کو مستقل اور مطلق وجود سمجھتے تھے۔ پچھلی صدی تک ہمیں وقت کی ناقابل یقین رفتار کا علم نہیں تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ جب اجسام کی رفتار بڑھتی ہے تو ان کا وقت سست ہو جاتا ہے اور "پھیل” جاتا ہے۔ اور جب وہ روشنی کی رفتار کے برابر ہو جاتے ہیں تو "وقت کا بہاؤ” رک جاتا ہے۔ ہاں، پیشرفت، آواز کی دیوار کی طرح، ایک اور…
"روشنی کی دیوار”
دکھا رہا تھا۔ جب روشنی کی رفتار حاصل ہو جائے گی تو وقت کے ساتھ ہم آہنگی ہو جائے گی اور وقت رک جائے گا۔ روشنی کی رفتار (300,000 کلومیٹر فی سیکنڈ) دراصل "وقت” کی رفتار بھی تھی۔
یہ بات سامنے آئی کہ وقت صرف رفتار پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ "کشش ثقل” سے بھی متاثر ہوتا ہے (عمومی اضافیت)۔ یہ بات پچھلی صدی کے اوائل میں سامنے آئی۔
"عمومی نظریہ اضافیت”
کے مطابق، موجودہ تین مکانی جہتوں کے
(لمبائی، چوڑائی، اونچائی)
اور ایک چوتھی جہت کے طور پر
"وقت”
شامل کیا جانا चाहिए था.
طول ایک سمت میں پھیلاؤ کا اظہار تھا۔ چونکہ نقطہ کسی سمت میں نہیں پھیلتا، اس لیے وہ بے جہت تھا۔ یہ معلوم تھا کہ لکیر ایک جہت کی حامل ہے، اور سطح دو جہتوں کی حامل ہے۔ تین جہتوں کا اظہار حجم سے کیا جاتا تھا۔ ہم ان تینوں کو پیمانے سے ناپ سکتے تھے، اور ان کو ہم مقام -مکان کے نقاط- کہتے تھے۔
لیکن چوتھی جہت،
وقت
ہم اسے کیسے ناپیں گے؟
وقت کو سمجھنے کی طرف لے جانے والی مطالعات
وقت کو فاصلوں کی طرح ایک مکانی خط کے طور پر سمجھنا بارہویں صدی تک جاتا ہے۔ اس حقیقت کا سب سے پہلا انکشاف الجبر کے بانی جابر نے کیا تھا۔
ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بعض چیزیں مطلق قدر کی حامل ہوتی ہیں، جبکہ بعض چیزیں اضافی ہوتی ہیں۔
بڑا-چھوٹا، لمبا-چوڑا، کڑوا-میٹها اور تیز-سست
یہاں کچھ اضافی اقدار ہیں. آئزک نیوٹن کے ساتھ، اشیاء کو سائنسی طور پر دو زمروں میں مطالعہ کیا جانے لگا۔ نیوٹن کے بعد، دو سائنسدانوں، مائیکل سن اور مورلی نے "ایتھر” نامی میڈیم کی تلاش کی. انہوں نے روشنی کی رفتار کی پیمائش سے متعلق متعدد تجربات کیے۔
ان کا خیال تھا کہ "روشنی کی رفتار مختلف ہوتی ہے”۔ ان مطالعات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ روشنی کی رفتار ہر سمت میں ایک مستقل اور اٹل قدر ہے، جو کہ 300,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔
یہی وہ ثابت قدمی تھی جس کی نیوٹن تلاش کر رہا تھا، لیکن افسوس، نیوٹن اب زندہ نہیں تھے۔ نیوٹن کے ساتھ ہی طبعی دنیا میں بڑے اجسام پر لاگو ہونے والے قوانین اور ضوابط، مادے کی طرح حرکت اور قوتوں کے بھی بے لگام نہ ہونے کا واضح ثبوت سامنے آ گیا تھا۔
نیوٹن کے زمانے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ روشنی ایک مستقل رفتار سے سفر کرتی ہے۔ چونکہ روشنی کی رفتار مستقل ہے، اس لیے اب ہر حرکت کو روشنی کی رفتار کے مطابق جانچا اور ناپا جا سکتا تھا۔ یہی بات وقت پر بھی لاگو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اب وقت کی پیمائش کے لیے ایک معیار موجود تھا۔ آئن سٹائن نے روشنی کی مستقل رفتار کے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی تلاش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔
کائنات ایک بہت بڑے پیمانے پر مجرد ڈھانچہ ہے۔ اس حقیقت کو جرمن سائنسدان اور مشہور ریاضی دان گاؤس نے زیر بحث لایا… اور مجرد کائنات کی ساخت کو ماڈلز کے ذریعے کسی حد تک سمجھنے میں گاؤس کے شاگرد ریمان نے کامیابی حاصل کی۔
رائمن کے تجریدی مکانی ابعاد کا اطلاق وقت پر آسٹریا کے ہرمن منکوفسکی نے کیا تھا۔ ریاضی میں جنہیں ہم خیالی اعداد کہتے ہیں
"مجرد یا پیچیدہ”
مِنکوفسکی نے ریاضیاتی طور پر یہ بھی ثابت کیا کہ وقت ایک نیا اور چوتھا طول و عرض ہے، جس میں اعداد میں سے ?-1 کا استعمال کیا جاتا ہے۔
مِنکوفسکی، آئن سٹائن کے ہائی اسکول کے ریاضی کے استاد تھے۔
وہ اس کا استاد/معلم تھا۔
آئن سٹائن نے ریمان سے خلاء کے تصور اور لورینز اور منکوفسکی سے وقت کے تصور کو اخذ کر کے ان کو یکجا کیا، جس کے نتیجے میں مشہور نظریہ اضافیت وجود میں آیا۔ چونکہ کائنات کے تمام واقعات اس مستقل روشنی کی رفتار کے مطابق ناپے جاتے ہیں، اس لیے اس نظریہ کا نام اضافیت رکھا گیا۔
آئن سٹائن نے خلا اور وقت کے ابعاد کو ایک دوسرے میں تبدیل کرنے کے بجائے، ان کو ایک ساتھ سوچنے کے خیال سے شروعات کی اور یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات نامی ماحول ایک خلا-وقت کا جال ہے۔ نتیجتاً، آئن سٹائن کا خلا-وقت چار ابعادی بن گیا۔ آئن سٹائن کا
"نظریہ اضافیت عام”
سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وقت کی رفتار کسی جسم کی رفتار اور اس کے کشش ثقل کے مرکز سے فاصلے کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے رفتار بڑھتی ہے، وقت سست ہوتا جاتا ہے، یعنی بھاری اجسام سست رفتار سے کام کرتے ہیں اور گویا "رک” جاتے ہیں۔
لورینٹز تبادلوں کے فارمولے آج بھی زمان و مکان کو جوڑنے والے اصل اضافیت کے فارمولے ہیں۔ زمان و مکان کی وحدت کو آئن سٹائن کے استاد ہرمن منکوفسکی نے ثابت کیا اور زمان کو ایک مجرد بُعد کے طور پر دریافت کیا۔ منکوفسکی نے بتایا کہ کائنات چار بُعدی ہے، زمان ایک خطی تسلسل رکھتا ہے، اور ماضی، حال اور مستقبل انسانی ذہن کی پیداوار ہیں۔ اس صورت میں، جس چیز کو ہم شعور کہتے ہیں، یعنی انسانی ادراک، پانچویں بُعد کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کے مطابق، شعور ایک مکانی خط پر سفر کرتے ہوئے ادراک کیے جانے والے زمان کے ایک ٹکڑے کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ کائنات کی اصل…
ذہن-عقل-شعور
جسے ہم پانچواں طول و عرض کہتے ہیں، وہ متعین کرتا ہے، سمجھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔
وقت،
اس کا ادراک دماغ میں محفوظ مختلف تصورات کے موازنے سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کی یادداشت نہ ہوتی تو دماغ اس طرح کی تشریحات نہیں کر پاتا اور اس طرح وقت کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ انسانی شعور "زمان و مکان” کے تصور میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ وقت کا ادراک اس پر منحصر ہے جو اس کا ادراک کرتا ہے، یعنی یہ ایک اضافی تصور ہے۔
وقت کی اضافیت
ہم اپنے خوابوں کے تجربات سے کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ خواب میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ گھنٹوں کا محسوس ہو، درحقیقت وہ چند سیکنڈ میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔
کائنات میں موجود تمام واقعات کے درمیان واقع اور ان کو آپس میں جوڑنے والا
"وقت”
اس اثر کے بغیر، ہم زندگی کو سمجھ نہیں پاتے، کائنات نامی اس عظیم خلا کو سمجھ اور بیان نہیں کر پاتے۔ زمان و مکان کی چار جہتی، ایک مشترکہ پیمائش کے نظام کے طور پر ظاہر ہوتی ہے، گوشت اور ناخن کی طرح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جس بات کو سمجھنے میں ہمیں دشواری نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ اس کا عمر کے ساتھ،
حادثہ – تقدیر
اس واقعے کو بھی چلاتا ہے، جو ایک تقدیر کے چارٹ کی طرح لگتا ہے۔ لہذا، وقت ہمارے سامنے ایک سکرین یا ایک ڈوری، ایک پٹی کے طور پر ظاہر ہوتا ہے جو تقدیر کو ظاہر کرتا ہے یا جس پر واقعات کی ترتیب لکھی ہوتی ہے۔
وقت بحیثیتِ بُعد
ہمارے ارد گرد
جگہ
ہم دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، ناپتے اور تولتے ہیں، اور "اس کے اندر” رہتے بھی ہیں۔
وقت
ہم کیوں نہیں دیکھ اور چھو سکتے؟
ان دو واقعات کا فرق یہ ہے کہ مکان کے نقاط ساکن اور جامد ہوتے ہیں، جبکہ وقت "روان”، متحرک اور "ناقابلِ دید” ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے ہم وقت کو آسانی سے سمجھ نہیں پاتے۔
وقت کو آسانی سے نہ سمجھ پانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مکانی ابعاد تو ثابت اور ٹھوس ہوتے ہیں، لیکن وقت کا بعد ان جسمانی وجود (مادے) کی قسم میں شامل نہیں ہے جنہیں ہم جانتے ہیں۔
ہم وقت کو ایک جہت کے طور پر کیسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی سے ملنے کے لیے "وقت” کا تعین نہ کریں، تو صرف جگہ بتانا کافی نہیں ہوگا۔
فرض کیجئے کہ آپ ایک خلائی جہاز میں ہیں، مثال کے طور پر، ایک ہیلی کاپٹر میں۔ آپ اپنے مقام کی اطلاع عرض البلد، طول البلد اور اونچائی کے زمینی نقاط کا ذکر کرتے ہوئے دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس وقت کے اپنے وقت، تاریخ اور گھنٹے کا بھی ذکر کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر، اس اطلاع کو عملی زندگی میں لانا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے لیے، زمان و مکان کا چار جہتی نظام ایک مشترکہ پیمائش کا نظام ہے۔ یہ گوشت اور ناخن کی طرح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔
اس طرح، وقت محض گھنٹوں کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کی طرح ایک جہت تھی۔ ہم وقت کو سمجھنے میں کیوں دشواری محسوس کرتے ہیں؟ اس کی وضاحت ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہماری بصری ادراک تین جہتوں کے لیے حساس ہے، اور دیگر جہتوں کے لیے نہیں۔ ہم چوتھی جہت، وقت کو، اسی طرح سمجھ نہیں پاتے جس طرح بہت سے جاندار گہرائی کی جہت کو نہیں سمجھ پاتے۔ بعض جانور اپنے ماحول کو دو جہتی، تصویر کی طرح دیکھتے ہیں۔ جس طرح بہت سے جانوروں کی دنیا سیاہ و سفید ہوتی ہے، اسی طرح ہم بھی دیگر جہتوں کو سمجھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ انسانوں کے پاس سب سے زیادہ ترقی یافتہ جذبات ہونے کے باوجود، ان کے جذبات اور حواس محدود ہیں۔ اس صورت میں، ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، اور سب کچھ کو اپنے حواس کی مشاہدات تک محدود کر سکتے ہیں؟
وقت کا دیگر جہتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، یعنی ان کے متناسب ہونا، اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ وقت ایک جہت ہے۔
وقت، مکانی ابعاد کے متوازی طور پر، عمل کے اعتبار سے بڑھتا یا گھٹتا ہے۔ وہیل مچھلیاں اوسطاً پانچ صدیاں، انسان 60-70 سال، اور خوردبینی کیڑے دو دن جیتے ہیں۔ سورج اور کائنات کی عمر اربوں سالوں میں بیان کی جاتی ہے۔ یہ میکرو عالم ہے۔ انتہائی چھوٹے ذرات، جو ایٹم سے بھی چھوٹے ہیں، کی دنیا میں اربوں سالوں کی جگہ اربوں میں سے ایک سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے۔
"عمر”
ہو جاتا ہے۔
بعض ذرات کی عمر اتنی مختصر ہوتی ہے کہ ان کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی وجہ سے ہم ان کو ذرہ نہیں بلکہ ریزوننس مانتے ہیں۔ ایٹمی سطح پر خلا کے سکڑنے کے ساتھ ہی اس کے مطابق "وقت کا سکڑنا” بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ وقت ایک جہت ہے۔
کائنات زمان و مکان کا ایک جال ہے. خلاء ہمیں تری آيامی نظر آتا ہے. وقت کو ایک طرف رکھ دیجئے؛ حالانکہ خلاء نامی مکان کے بھی 3 سے زیادہ آيام ہیں. مکان کا چوتھا آيام کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کی وضاحت تو دور کی بات، اس کا تصور کرنا اور اس کو تخیل میں لانا بھی بہت مشکل ہے. لمبائی، چوڑائی اور اونچائی مکان کے تین آيام ہیں، ایک چوتھا آيام کیا ہو سکتا ہے؟ ہم "سرنگ” کہتے ہیں، لیکن اس اعلیٰ مکانی آيام کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا.
اگر کسی چیز کی لمبائی a ہے، رقبہ a2 ہے، اور حجم a3 ہے، تو a4 کیا ہے؟
اگر ہم خلا کو ایک ہموار کاغذ کی طرح مان لیں، تو اس کاغذ کی کوئی گہرائی نہیں ہے۔ یعنی کاغذ کی صرف سطح ہے۔ آپ اس لچکدار کاغذ کو چاہیں تو شنک بنا لیں، "شوارزچائلڈ شنک” بنا لیں، یا چاہیں تو کرہ کی سطح کی طرح گول کر لیں، "ریمان اسپیس” حاصل کر لیں۔ چونکہ یہ ہمیشہ کاغذ سے جڑا رہتا ہے، اس لیے یہ کاغذ ہمیشہ دو جہتی رہتا ہے۔ تیسرا جہت تبھی بنتا ہے جب آپ گہرائی پیدا کریں، یعنی جب آپ کاغذ کے نیچے یا اوپر جائیں۔ ورنہ کاغذ چاہے جتنا بھی شنک یا کچھ اور ہو، جب تک آپ اس کی سطح پر ہیں، وہ "دو جہتی” ہے۔
چونکہ چوتھے مکانی محور، یعنی سرنگ کو سمجھنا مشکل ہوگا، اس لیے اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے، آئیے ہم اپنے کائنات کو "دو جہتی” یعنی ایک ہموار سطح، ایک کاغذ کے طور پر تصور کریں۔ اس سطح پر ہم بغیر موٹائی کے فوٹو کی شکل میں انسان ہیں۔ بالکل اخبار پر موجود بغیر گہرائی کے نقشوں کی طرح۔ ہم اس کاغذ پر ہر طرف جانے کے لیے آزاد ہیں؛ یعنی ہمارے پاس چار سمتوں کا احساس ہے۔
لیکن چونکہ ہم اس کاغذی سطح سے کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے، اس لیے ہم اوپر اور نیچے کی اصطلاحات سے واقف ہی نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ہمیں بتائے بھی تو ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ اس طرح ہمیں تیسری جہت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، اور ہماری لغت میں "اوپر، نیچے” کی اصطلاح موجود نہیں ہوگی۔ اب چوتھی جہت کے بارے میں ہماری لاعلمی بھی اسی طرح کی ہے۔
اگر ہمارے کاغذی جہان سے اوپر کوئی سہ جہتی جسم ہو، اور وہ جسم ہمارے کاغذ کو چیر کر گزر بھی جائے، تب بھی ہم اسے سہ جہتی طور پر نہیں دیکھ پائیں گے، بلکہ صرف اس کے اس حصے کو دیکھیں گے جو ہمارے جہان سے متصل ہے۔ مثال کے طور پر، اگر وہ ایک کرہ ہو، تو ہم اس کے پروجیکشن، یعنی اس کے مقطع یا سائے کو ایک دائرے کے طور پر دیکھیں گے۔
ایسا سہ جہتی جسم، چونکہ ہم اس کا مقطع دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں "دو جہتی” نظر آتا ہے۔ اور ہم حیران بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ اچانک "موجود” ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ہمارے کاغذی کائنات سے گزرنے والا ایک کرہ ہے، تو اس کے عرض البلد کے مقاطع قطبوں سے شروع ہو کر بتدریج بڑھتے ہیں، خط استوا پر سب سے بڑا دائرہ بنتا ہے اور پھر گھٹتے ہوئے حلقے کی شکل میں دوسرے قطب پر غائب ہو کر "نیچے” چلا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے نمونے ثابت ہیں، اس لیے ہم اس کے اچانک ظاہر ہونے، بڑھنے، گھٹنے اور غائب ہونے کو ایک ناقابل یقین واقعہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنی دنیا میں بہت سے مافوق الفطرت واقعات کو ناقابل یقین مانتے ہیں…
ہمارے علاوہ ایک چار جہتی جسم
"تین جہتی”
اس کا سایہ ہمارے سہ جہتی خلا پر پڑتا ہے۔ جس طرح ایک دائرہ ایک دائرے کی طرح نظر آتا ہے، ہم سرنگوں کی لمبائی نہیں دیکھتے؛ بلکہ ان کا مقطع دیکھتے ہیں۔
دائرہ
چونکہ ایک سادہ سی شے نے ہمیں حیران کر دیا ہے، تو اب ایک زیادہ پیچیدہ شکل پر غور کیجئے۔ مثال کے طور پر، ایک گلدان کا سایہ دیوار پر ڈالیں اور گلدان کو گھما کر مختلف اور ناقابل فہم سائے بنائیں۔ دیوار پر لگی ایک تصویر، اس سایے اور اس کے تغیرات کو حیرت سے دیکھے گی، ڈر جائے گی۔ کیونکہ وہ بے قد انسان، ہمیں اور گلدان کو نہیں، صرف دیوار پر پڑنے والے سایے کو دیکھتا ہے۔ اس کے لئے دیوار اس کی کائنات ہے، دیوار کے باہر اور پیچھے کچھ نہیں ہے۔ ہم اسے بتائیں بھی تو وہ یقین نہیں کرے گا۔
چونکہ ہم ایک ہی زمان و مکان کے دائرے میں قید ہیں، اس لیے ہم واقعات کا جائزہ محدود مکانی حدود اور مخصوص ابعاد میں لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی سے مراد حجم و فضا کا تصور قابل فہم ہے۔ لیکن چوتھا بعد، یعنی وقت، اگرچہ فزکس اور نظریہ اضافیت میں شامل ہے، ایک (مجرد) لمبائی ہے، مادہ سے ماورا ہے۔ پانچواں بعد، جس کا تذکرہ ٹیکیون کے نظریہ میں ملتا ہے اور جس سے مراد عقل و شعور ہے، وقت کی طرح مجرد ہے، مادی نہیں ہے۔
سرنگ کا عمل
اور ہمیں یہ ایک ناقابل یقین حد تک بڑا طول و عرض نظر آتا ہے۔ کائنات میں ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، وہ کثیر الابعاد اجسام کا سہ جہتی سایہ اور پروجیکشن ہے۔ دراصل، ماوراء الطبیعی واقعات اور وجودات، جنہیں ہم ماوراء الطبیعی اور ماوراء نفسیاتی اصطلاحات میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ہم پر پڑنے والا اثر اسی طرح نظر آتا ہے۔
سرنگوں میں مخلوقات، موجودات ہیں (جو ہماری تین جہتوں کے باہر چوتھی جہت میں پنہاں ہیں)۔
ان میں روح اور روح سے متعلق جذبات، یا فرشتوں اور جنوں جیسے باشعور مخلوقات سے ہم تک پہنچنے والی چیزیں شامل ہیں، جنہیں ہم اس زمرے میں شامل کر سکتے ہیں۔ اشیاء کا کشش ثقل کے خلاف ہوا میں اڑنا اور فرشتوں کا اڑنا جیسے واقعات ہمیں حیرت انگیز لگتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارے تابع فزکس کے قوانین سے باہر ہیں۔ حالانکہ وہ اشیاء پانچویں جہت (یا کائنات کے چوتھے مکانی جہت یا تیسرے سطح) میں اڑ رہی ہیں۔
نظریہ اضافیت اور وقت
وقت کی رفتار اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اس کی پیمائش کے لیے کس قسم کے حوالے استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان کے جسم میں کوئی ایسا قدرتی گھڑیال نہیں ہے جو وقت کی رفتار کو مطلق درستگی سے ظاہر کرے۔ اس لیے مختلف قسم کے وقت کا تصور موجود ہے۔ جس طرح اگر دماغ اور آنکھیں رنگوں کو پہچاننے کی صلاحیت نہ رکھتیں تو رنگ کا کوئی وجود نہ ہوتا، اسی طرح جب تک کوئی واقعہ یا حرکت وقت کو ظاہر نہ کرے، تب تک ایک لمحہ، ایک گھنٹہ یا ایک دن کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بہت سے جانوروں کے دماغ میں رنگوں کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ بے رنگ دنیا میں رہتے ہیں، اور بہت سے جانوروں میں گہرائی کا ادراک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ دو جہتی ادراک کرتے ہیں۔
آئیے ہم کسی ایک واقعے کے "الگ الگ” ادراک پر غور کریں، جو ہماری دوری پر منحصر ہے۔
مثال کے طور پر، سورج میں ہونے والا ایک دھماکہ زمین پر 8 منٹ بعد، قریبی ستارے پر 4 سال 4 ماہ بعد، ایک دور ستارے پر 1400 سال بعد اور قریبی کہکشاں میں تقریباً 30 لاکھ سال بعد دیکھا جاتا ہے۔ علم نجوم میں، چونکہ ہم آسمانی اجسام سے آنے والی شعاعوں کے ذریعے خبریں حاصل کرتے ہیں، اس لیے ہم کائنات کے ماضی کو دیکھ رہے ہیں۔
جیسا کہ دیکھا گیا ہے، ایک واحد واقعہ ہزاروں مجرد واقعات میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وقت ایک ٹھوس نہیں بلکہ ایک مجرد بُعد ہے۔ روشنی کی رفتار کے مقابلے میں، دیگر چیزیں نسبتی رہتی ہیں۔ یہی نسبیت کے نظریہ کا ایک مفہوم ہے۔
پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب اجسام کی رفتار بڑھتی ہے تو ان کی مطلق سمجھی جانے والی اقدار میں تبدیلی آتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کیجئے کہ ہم کسی جسم، مثلاً کسی انسان کو، روشنی کی رفتار کے 99.9 فیصد تک تیز کرتے ہیں۔ عام طور پر اس کی وضاحت دو جڑواں افراد کی مشہور مثال سے کی جاتی ہے جن کی پیدائش کی تاریخ ایک جیسی ہے۔ ان میں سے ایک شخص زمین پر ہے، اور دوسرا ایک خلائی جہاز میں روشنی کی رفتار کے قریب سفر کر رہا ہے۔ اس دوسرے شخص کا وقت ہمارے وقت کے مقابلے میں 14 گنا سست ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ ایک سال بڑا ہو گا، ہم 14 سال بڑے ہو جائیں گے۔
یہ تبدیلی صرف اتنی ہی محدود نہیں رہے گی۔ روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرنے والے جڑواں کی لمبائی آدھی رہ جائے گی۔ اس کے ہاتھ میں موجود ایک میٹر لمبی چیز 50 سینٹی میٹر رہ جائے گی۔ اس کا وزن تین گنا بڑھ جائے گا، 70 کلوگرام سے 210 کلوگرام تک پہنچ جائے گا۔ دراصل، نظام کے اندر موجود شخص کے مطابق، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ کیونکہ جس نظام میں وہ موجود ہے، اس میں بھی اس کے متناسب متوازی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ ہاں، یہی سب کچھ ہے اور یہ واقعی حیران کن ہے۔
نظام کو تشکیل دینے والے ایٹموں کی لمبائی بھی کم ہو رہی ہے، ان کا وزن بڑھ رہا ہے اور ان کا وقت سست ہو رہا ہے، لیکن ہمارے خلا نورد کو کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ کیونکہ ہر نظام دوسرے نظام کو اپنے ہی اقدار سے ماپتا ہے۔ "جڑواں کا تضاد” کو اضافیت کا نظریہ اس مفروضے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ "تمام مبصرین جو دیکھتے ہیں وہ سچ ہے۔”
خصوصی اضافیت کا یہ اصول یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہی واقعہ کا فاصلہ اور رفتار کے لحاظ سے ہر مشاہد کے مطابق الگ الگ نظر آنا، مشاہدین کے مابین تضاد پیدا کرتا ہے اور ہر مشاہد درست ہوتا ہے۔ جیسا کہ دیکھا گیا ہے، وقت ایک مطلق قدر نہیں ہے، بلکہ ایک اضافی تصور ہے جو رونما ہونے والے واقعات کے مطابق مختلف طور پر محسوس کیا جاتا ہے۔
تاہم، وقت کا رشتہ دار ہونا گھڑیوں کے سست یا تیز ہونے سے نہیں، بلکہ تمام مادی نظام کے ذیلی ایٹمی سطح کے ذرات تک مختلف رفتار سے کام کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ وقت کے مختصر ہونے والے ایسے ماحول میں، انسانی جسم میں دل کی دھڑکن، خلیوں کی تقسیم، دماغی سرگرمیاں وغیرہ سست ہو جائیں گی۔ اس طرح، فرد وقت کے سست ہونے کا احساس کیے بغیر اپنی روزمرہ کی زندگی بسر کرتا ہے۔
چونکہ ہمارا دماغ ایک خاص ترتیب کے مطابق کام کرتا ہے، اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ وقت ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے دماغ کے اندر لیا گیا ایک فیصلہ ہے اور اس لیے یہ مکمل طور پر نسبی ہے۔ اگر ہماری یادداشت میں موجود معلومات الٹی فلموں کی طرح ترتیب دی جائیں، تو وقت کا بہاؤ بھی ہمارے لیے الٹی فلموں کی طرح ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں، ہم ماضی کو مستقبل اور مستقبل کو ماضی کے طور پر سمجھنا شروع کر دیں گے، اور زندگی کا ایک بالکل الٹا نظام سامنے آ جائے گا۔
جس طرح خلا مادی وجودات کا ایک ممکنہ سلسلہ اور نظم ہے، اسی طرح وقت بھی ایک طرح سے واقعات کا ایک ممکنہ سلسلہ ہے۔ فرد کے تجربات ہمیں واقعات کے ایک سلسلے میں منظم نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے سے جن واقعات کو ہم یاد رکھتے ہیں، وہ ‘پہلے’ اور ‘بعد’ کے پیمانے کے مطابق ترتیب وار معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے ایک "میں” کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت اپنے اندر ناپا نہیں جا سکتا۔ ہم واقعات اور اعداد کے درمیان اس طرح کا تعلق قائم کر سکتے ہیں کہ ایک بڑا عدد کسی پچھلے واقعے سے نہیں بلکہ کسی بعد کے واقعے سے متعلق ہو۔
نوبل انعام یافتہ جینیات کے پروفیسر اور مفکر فرانسوا جیکب،
"ممکنات کا کھیل”
اپنی کتاب میں، وہ وقت کے الٹے بہاؤ کے بارے میں درج ذیل بتاتے ہیں:
"الٹی ترتیب میں دکھائی جانے والی فلمیں،”
یہ ہمیں اس بات کا تصور کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ایسی دنیا کیسی ہوگی جس میں وقت الٹا بہتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں دودھ کپ میں موجود کافی سے الگ ہو جائے گا اور دودھ کے برتن تک پہنچنے کے لیے ہوا میں اچھل جائے گا؛ ایک ایسی دنیا جہاں روشنی کی شعاعیں ایک منبع سے نکلنے کے بجائے ایک جال (کشش کے مرکز) میں جمع ہونے کے لیے دیواروں سے نکلیں گی؛ ایک ایسی دنیا جہاں لاتعداد قطروں کے حیرت انگیز تعاون سے پانی سے باہر پھینکا گیا ایک پتھر ایک انسان کے ہاتھ میں آنے کے لیے ایک خمیدہ راستہ بنائے گا۔ لیکن ایسی دنیا میں جہاں وقت الٹ دیا گیا ہے، ہمارے دماغ کے عمل اور ہماری یادداشت کی تشکیل بھی اسی طرح الٹ دی جائے گی۔ ماضی اور مستقبل کے لیے بھی یہی بات ہوگی اور دنیا بالکل ویسی ہی نظر آئے گی جیسی ہمیں نظر آتی ہے۔” (فرانسوا جیکب، ممکنات کا کھیل، کیسیت پبلیکیشنز، 1996، ص. 111)
وقت کی تغیر پذیری
چونکہ نصف حیات ایک اٹل طبعی-ریاضیاتی اصول ہے، تو پھر وہ ذرات، جیسے ہائپرون کوانٹم، کائناتی پرائمری، سیکنڈری، یا کائناتی شعاعیں، جن کی عمر ایک سیکنڈ کے اربویں حصے کے برابر ہے (یعنی ان کا بننا اور ختم ہونا ایک ساتھ ہے)، سورج یا چاند سے ہم تک کیسے پہنچ پاتے ہیں؟
ایسے ذرات کو خلاء سے زمین تک پہنچنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی یہ ذرات زمین پر پائے اور دیکھے جا سکتے ہیں!
اس ناقابل یقین حقیقت کے پیش نظر، سائنسدانوں نے اس واقعے کا جائزہ "وقت کے طویل یا مختصر ہونے” کے زمرے میں لینا شروع کر دیا۔ یعنی، چونکہ "آدھی عمر” ایک ریاضیاتی حقیقت ہے، اس لیے مختلف مکانی حصوں میں وقت کا بہاؤ مختلف ہونا چاہیے تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وقت ہر جگہ ایک ہی رفتار سے نہیں بہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا مختلف مقامات پر مختلف اثر اور انعکاس ہوتا ہے، اور موجودات کی عمریں مختلف مقامات پر مختلف ہوتی ہیں۔
کائنات میں بعض شعاعی ذرات ایسے ہیں جن کی عمر محدود اور متعین ہوتی ہے۔ ان کی نصف عمر اتنی مختصر ہوتی ہے کہ وہ ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک کا سفر نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر، پائی اور ایٹا میسون، جو بھاری الیکٹران کی ایک قسم ہیں، ان میں سے کچھ ہیں۔ ان کی نصف عمر اتنی مختصر ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے دس لاکھویں حصے کے برابر ہے۔ اتنی مختصر عمر کے ساتھ، وہ صرف چند سو میٹر کا فاصلہ طے کر پاتے ہیں۔ تو پھر یہ سورج یا دوسرے ستاروں سے ہماری زمین تک کیسے پہنچ پاتے ہیں؟ اس کا صرف ایک ہی جواب نظر آتا ہے: "وقت کا پھیلاؤ”۔ پرانے زمانے کے الفاظ میں، "بستِ زمان”۔ ہم اضافیت کے نظریہ سے جانتے ہیں کہ تیز رفتار اجسام میں وقت "پھیلتا” ہے۔ متعلقہ جسم زیادہ "جوان” رہتا ہے۔ "وقت کا پھیلاؤ” راکٹ یا تیز رفتار جیٹ میں بھی تصدیق کیا گیا ہے۔ وقت کا سست ہونا، پروٹون اور نیوٹران کے تیز کرنے اور لیزر گھڑیوں سے حساس پیمائشوں سے بھی تصدیق کیا گیا ہے۔ اضافیت کے نظریہ کی تصدیق کے لیے اس سے بہتر ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟
اس طرح کے ثبوت فراہم کرنے والے ذرات میں سے ایک میون نامی ذرہ ہے۔ یہ ایک ضمنی پیداوار ہے جو خلا سے آنے والی ابتدائی شعاعوں کے، فضا میں موجود آکسیجن اور نائٹروجن کے مرکزوں سے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے فضا کے 30-60 کلومیٹر اوپر بننے والے میون دراصل ایک سیکنڈ کے دس لاکھویں حصے میں الیکٹران میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ اس وقت میں (ایک سیکنڈ کے دس لاکھویں حصے میں) شعاعیں صرف 300 میٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ میون پوری فضا کو پار کرنے کے بعد سمندروں کے تین میٹر نیچے تک پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میون کی روشنی کے بہت قریب رفتار کی وجہ سے ان کا وقت پھیلتا ہے اور ان کی عمر 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔
"جڑواں بچوں کا تضاد”
جس مثالی تجربے کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں چونکہ کوئی بھی لیبارٹری ہمیں روشنی کی رفتار کے قریب رفتار فراہم نہیں کر سکتی، اس لیے ہم اپنے دماغ میں ایک خیالی مشق کے ذریعے وقت کے سکڑاؤ کو بہتر طور پر سمجھا سکتے ہیں۔ یہاں جڑواں بھائیوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک ہمارے ساتھ زمین پر رہے گا، اور دوسرا جڑواں بھائی ایک خلائی جہاز میں خلا نورد ہے جو روشنی کی رفتار کے قریب رفتار سے سفر کر رہا ہے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے: یہ دوسرا جڑواں بھائی اپنے زمینی جڑواں بھائی کے "حال” سے آگے نکل جائے گا اور اس کے مستقبل میں داخل ہو جائے گا۔ یہ تضاد روشنی کی رفتار کے قریب رفتار پر گھڑی کے سست ہونے اور مکمل روشنی کی رفتار پر گھڑی کے مکمل طور پر رک جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ دراصل، ہماری گھڑی میں کوئی میکانیکی یا الیکٹرانک خرابی نہیں ہے۔ یہ واقعہ براہ راست وقت کے سکڑاؤ کا ہے۔ وقت کے سکڑاؤ کا ریاضیاتی اظہار اس وقت اور واضح ہو جاتا ہے جب ہم لورینٹز کے تبادلاتی فارمولے کا استعمال کرتے ہیں۔ روشنی کی رفتار کے 87% کی رفتار سے سفر کرنے والے خلائی جہاز میں موجود جڑواں بھائی، باہر سے دیکھنے والے ایک مبصر کے مقابلے میں دو گنا سست ہو جاتا ہے۔ اس طرح، زمینی جڑواں بھائی کے دو سال بوڑھے ہونے کے مقابلے میں، خلائی جہاز میں موجود جڑواں بھائی صرف ایک سال بوڑھا ہو گا۔
اب اس فارمولے کو 90 فیصد روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والے ایک نظام پر لاگو کرتے ہیں۔ خلا نورد جڑواں دیکھے گا کہ اس کا وقت زمین پر موجود جڑواں کے وقت کے مقابلے میں دس گنا سست ہو گیا ہے۔ اس طرح زمین پر موجود جڑواں کے ہر دس سال یا عمر کے بدلے، خلا نورد جڑواں صرف ایک سال بوڑھا ہو گا۔ جب ہم اسی فارمولے کو 99.99 فیصد روشنی کی رفتار پر لاگو کرتے ہیں، تو زمین پر موجود جڑواں کے ہر 18 سال کے بدلے، خلا نورد جڑواں صرف ایک سال بوڑھا ہو گا۔ اگر ہم اس سفر کے وقت کو ایک دن یا ایک مہینے تک بڑھا دیں، تو واپسی پر، خلا نورد جڑواں حیرت سے دیکھے گا کہ اس کا جڑواں مر چکا ہے اور اس کی نسل کے پوتے بھی اس سے بوڑھے ہیں۔ اس طرح کے سفر پر جانے والا خلا نورد جڑواں کبھی اپنے دور میں واپس نہیں آ سکے گا۔ عمر بڑھنے کی سست روی تمام حیاتیات کو بھی متاثر کرتی ہے۔ کیونکہ خلا نورد جڑواں کی دل کی دھڑکن، سانس اور دیگر جسمانی نظام، زمین پر موجود جڑواں کے مقابلے میں 70,000 گنا کم کام کر رہے ہیں۔
"مِنکوفسکی” کے ریاضی نے ثابت کیا ہے کہ وقت کا پھیلنا اور سکڑنا، عمر کا بڑھنا اور گھٹنا، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کے طول و عرض کے ساتھ یکساں طور پر مطابقت رکھتا ہے۔ وقت کی رفتار متعین نہیں ہے، وقت کا بہاؤ زمین پر، ایٹم میں، خلا میں، مختلف اور لچکدار ہے؛ اس میں فرق ہو سکتا ہے۔
اس حقیقت کے ساتھ جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ ہے ہمارے دور کے حسابات پر نظرثانی کی ضرورت۔ دراصل، چونکہ آسمانی اجسام اور زمین، جانداروں اور انسانیت کی تاریخ کا حساب نسبتاً اور موٹے طور پر، عام طور پر سادہ حرارت کے اصولوں پر مبنی ہے (مثلاً کہکشاؤں اور سپرنووا کے ٹھنڈے ہونے کے دورانیے کی طرح)، اس لیے ان دورانیوں پر یقین کرنا مشکل ہے۔ ابتدائی دور میں جانداروں کے بہت بڑے سائز سے ہمیں اس دور میں وقت کے بہاؤ کے مختلف ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سائز بڑھتا ہے، وقت کے طول و عرض کا دوسرے طول و عرض کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا بائیو جیومیٹری کے قانون کے طور پر بھی متعین کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق، اس دور میں جانداروں کی طویل عمر کے ساتھ ساتھ وقت کا سست بہاؤ، حاصل کردہ بعض سائنسی اشاروں اور آسمانی کتابوں کے اشاروں سے تصدیق شدہ ہے۔
اقلیدس کے ویکٹر اسپیس میں، سہ جہتی خلا اور ہم جہتی وقت کو ایک ہی چیز کے طور پر سمجھا جاتا تھا، وقت کے لیے کوئی الگ فنکشن نہیں سوچا گیا تھا اور کائنات کو مستحکم اور ساکن رہنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ لیکن اضافیت کے مطابق کائنات متحرک اور حرکت میں ہے۔ اضافیت نے صرف وقت ہی نہیں بلکہ کمیت، لمبائی اور خلا کے تصورات کو بھی ثابت نہیں مانا، بلکہ یہ ظاہر کیا کہ یہ نظام کے پیمائشی قدر کے مطابق بدلتے ہیں۔ اس طرح، وقت کے مطلق ہونے اور کائنات کے ہر طرف یکساں طور پر بہنے، تمام مخلوقات اور اکائیوں کے لیے ایک ہی اور سادہ تصور ہونے کا نظریہ بنیادی طور پر بدل گیا۔ اور ہمارے ذہن میں جمے ہوئے خیالات میں انقلاب لایا۔ یہ اتنا اہم انقلاب تھا کہ اس نے لامحدود خلا اور مختلف طرز زندگی کو منظر عام پر لایا۔
وقت مطلق نہیں ہے،
اور یہ بھی کہ وہ (انسان) پیدا کیا گیا ہے اور خاص طور پر تغیر پذیر ہے، (اس بات کا ثبوت) ہماری مقدس کتاب (قرآن) میں موجود ہے۔
قرآن میں
یہ اس لافانی زندگی (ابدی حیات) کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان پیشرفتوں کے نتیجے میں، ایک اور نکتہ جس کو ہم بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ، جو وقت کو ایک رسی اور فیتے کی طرح بنا کر اس پر واقعات کو ترتیب دیتا ہے اور ہر چیز کی طرح وقت کا بھی خالق ہے، وقت کی قید سے آزاد ہوگا اور اس کے لیے کوئی ابتدا اور انتہا تصور نہیں کی جا سکتی۔
سلام اور دعا کے ساتھ…
سوالات کے ساتھ اسلام